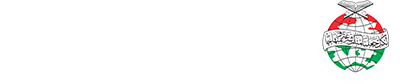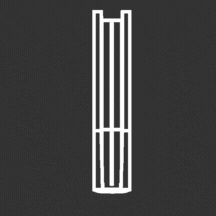مشرق و مغرب کے مفکرین اور شعراء میں علامہ محمد اقبال کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انھوں نے فکرِ انسانی کے مشترک موضوعات اور مسائل پر اس انداز سے غوروفکر کیا ہے کہ اس سے ان مسائل کی آفاقی جہات متعارف ہوئیں۔ ایسی فکر کسی تہذیب یا علاقے تک محدود نہیں رہتی بلکہ پوری انسانیت کے مسائل کو اپنا موضوع بنالیتی ہے۔ اقبال نے انسانیت کے مسائل کو اپنی نثر اور نظم دونوں میں موضوع بحث بنایا ہے لیکن امتیاز یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کا یہ بیان صرف استدلال پر ہی مبنی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پیغمبرانہ تیقن بھی روح کی طرح کارفرما ہے۔ ذیل میں تین جہات سے علامہ محمد اقبال کی فکر کو قومی و ملی سطح پر راہنمائی کے تناظر میں بیان کیا جارہا ہے:
1۔ دینی اور ملی اساس
اقبال نے انسان کے بنیادی سوالات کو اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں پیش کیا ہے کہ ہمارا تصورِ خدا، تصورِ کائنات اور تصورِ انسان کیا ہونا چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان بنیادی سوالات کا جواب دیتے ہوئے اقبال ایک ایسی مضبوط اساس پر کھڑے ہیں جہاں ہم دینی اور ملی حوالے سے اقبال کی فکر کو مستند قرار دے سکتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ کی ذات مبارکہ سے تعلق، قرآن حکیم کے ساتھ وابستگی اور اسلام کی فکری روایت سے استشہاد اقبال کو مضبوط دینی اور ملی اساس فراہم کرتے ہیں:
(1)حضور علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ سے تعلق
حضور اکرم ﷺ کی ذات مبارکہ سے تعلق علامہ محمد اقبال کی شخصیت کااہم پہلو ہے۔ اقبال کے فکروعمل میں یہ تعلق ایک مرکز و محور کی حیثیت رکھتا ہے جو نہ صرف ان کی فکری کاوشوں بلکہ عملی رویوں کی سمت کا تعین بھی کرتا ہے۔ اقبال دین کی حقیقت سے آگاہی کے لیے نسبت محمدی ﷺ کو ناگزیر قرار دیتے ہیں۔ خان نیاز الدین خان کے ایک مکتوب کے جواب میں فرماتے ہیں:
’’نبی اکرم ﷺ کی زیارت مبارک ہو۔ اس زمانے میں یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ دوسری رؤیا کا بھی مفہوم یہی ہے۔ قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تاکہ قلب، محمدی نسبت پیدا کرے۔ اس نسبتِ محمدیہ کی تولید کے لیے یہ ضروری نہیں کہ قرآن کے معانی بھی آتے ہوں۔ خلوص و محبت کے ساتھ محض قرأت کافی ہے۔ ‘‘
(خطوط اقبال، رفیع الدین ہاشمی، ص: 107)
ó علامہ محمد اقبال کی اکثر شعری تخلیقات بھی اسی نسبت اور تحریک کے تحت وجود میں آئیں۔ اپنی نظم ’’در حضور رسالتمآب‘‘ کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:
’’میں نے سرسید ؒ کو خواب میں دیکھا۔ پوچھتے ہیں کہ تم کب سے بیمار ہو؟ میں نے عرض کیا: دو سال سے اوپر مدت گزر گئی۔ فرمایا: حضور رسالتمآب ﷺ کی خدمت میں عرض کرو۔ میری آنکھ اسی وقت کھل گئی اور اس عرضداشت کے چند شعر، جو اب طویل ہوگئی ہے، میری زبان پر جاری ہوگئے۔
(اقبال نامہ، مجموعہ مکاتیب اقبال، شیخ عطاء اللہ، ص: 306)
ó علامہ محمد اقبال ملتِ اسلامیہ کی تہذیبی زندگی کی بقا اتباعِ نبوی ﷺ میں دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں:
جہاں تک فرد کی ذات اور معاشرے کی تہذیب و ترقی یا دوسرے لفظوں میں معراجِ انسانیت کا تعلق ہے، یہ مقصد حضور رسالت مآب ﷺ کی اتباع ہی سے حاصل ہوگا۔ البتہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی نصب العین ہو اس کے لیے یقینِ کامل شرط ہے۔ یقین نہیں تو عمل بھی نہیں، نہ آزرو، نہ ولولہ، نہ جدوجہد۔
(اقبال کے حضور، سید نذیر نیازی، ص: 62)
ó یہی نکتہ اپنے تمام فکری سفر میں اقبال کے پیش نظر رہا۔ مثنوی اسرار و رموز کی تصنیف کے بارے میں فرماتے ہیں:
میرا مقصد کچھ شاعری نہیں بلکہ ہندستان کے مسلمانوں میں وہ احساسِ ملیہ پیدا ہو، جو قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کا خاصہ تھا۔ اس قسم کے اشعار لکھنے سے غرض عبادت ہے اور نہ شہرت۔ کیا عجب کہ نبی کریم ﷺ کو میری یہ کوشش پسند آجائے اور ان کا استحسان میرے لیے ذریعہ نجات ہوجائے۔
(اقبال، جناح اور پاکستان، صفدر محمود، ص: 136)
(2) قرآن مجید کے ساتھ وابستگی
علامہ محمد اقبال قرآن حکیم کو مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں ارتقائی نقطہ نظر کو اقبال دوامی اور وقتی؛ ہر دو زاویوں سے دیکھتے اور پرکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن حکیم کی ابدی تعلیمات تو اٹل ہیں، ان میں کبھی کوئی تبدیلی ممکن نہیں مگر ان بنیادی تعلیمات پر قائم رہتے ہوئے بدلتی ہوئی زندگی کے تقاضوں اور نئے علوم کی روشنی میں ہمیشہ ان کی از سر نو تفسیر کرنے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ (اقبال فراموشی، فتح محمد ملک، ص: 170)
ó قرآن حکیم سے یہ تعلق اقبال کی بچپن کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے علامہ نے فرمایا:
قرآن مجید دل کے راستے بھی شعور میں داخل ہوتا ہے۔ یہ حقیقت یوں سمجھ میں آئے گی کہ یہ کالج میں میری تعلیم کا ابتدائی زمانہ تھا۔ میرا معمول تھا کہ ہر روز نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ اس دوران میں والد ماجد بھی مسجد سے تشریف لے آتے اور مجھے تلاوت کرتا دیکھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ میں کبھی ایک منزل ختم کرچکا ہوتا کبھی کم۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ والد ماجد حسبِ معمول مسجد سے واپس آئے، میں تلاوت میں مصروف تھا۔ مجھے فرمایا کہ قرآن حکیم اس طرح پڑھو گویا تم پر نازل ہورہا ہے۔
(اقبال کے حضور، سید نذیر نیازی، ص: 60)
ó عام مسلمان کی زندگی میں قرآن حکیم سے تعلق کی اہمیت بیان کرتے ہوئے میاں رشید احمد سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا:
دیکھو تم ہی کو اب یہاں رہنا ہے۔ ہم تو مسافر ہیں۔ یاد رکھو! مسلمانوں کے لیے جائے پناہ صرف قرآن کریم ہے۔ زمانے کے ساتھ ضرور چلنا چاہیے لیکن اپنے دامن کو اس کے بداثرات سے آلودہ نہ ہونے دو۔ میں اس گھر کو صد ہزار تحسین کے قابل سمجھتا ہوں جس گھرسے علی الصبح تلاوت قرآن مجید کی آواز آئے۔ کلام مجید کا صرف مطالعہ ہی نہ کیا کرو بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔
(گفتارِ اقبال، محمد رفیق افضل، ص: 213)
ó علامہ محمد اقبال خود بھی قرآن حکیم کی تفسیر لکھنا چاہتے تھے۔ راس مسعود کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:
تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے قرآن کریم سے متعلق اپنے افکار قلمبند کرجاؤں۔ جو تھوڑی سی ہمت و طاقت ابھی مجھ میں باقی ہے، اسے اسی خدمت کے لیے وقف کردینا چاہتا ہوں تاکہ (قیامت کے دن) آپ کے جد امجد (حضور نبی اکرم ﷺ ) کی زیارت مجھے اس اطمینان خاطر کے ساتھ میسر ہو کہ اس عظیم الشان دین کی جو حضور نے ہم تک پہنچایا، کوئی خدمت بجا لاسکا۔
(اقبال نامہ، مجموعہ مکاتیب اقبال، شیخ عطاء اللہ، ص: 273)
ó دہلی میں 9 ستمبر 1931ء کو ایک تقریب میں فرمایا:
جہاں تک سیاسی مسائل کا تعلق ہے، میں آپ کو بتادینا چاہتا ہوں کہ نہ میرے ساتھ کوئی پرائیویٹ سیکرٹری ہے جو میرے لیے ضروری مواد فراہم کرے، نہ میرے پاس سیاسی لٹریچر کا کوئی پلندہ ہے جس پر میں اپنی بحثوں کی اساس قائم کروں بلکہ میرے پاس حق و صداقت کی ایک جامع کتاب (قرآن پاک) ہے جس کی روشنی میں میں مسلمانانِ ہند کے حقوق کی ترجمانی کرنے کی کوشش کروں گا۔
(گفتارِ اقبال، محمد رفیق افضل، ص: 136)
(3) صوفیاء سے فکری و عملی تعلق
اسلام کی فکری روایت اور صوفیائے اسلام سے فکری اور عملی تعلق علامہ محمد اقبال کی شخصیت کا اہم حصہ ہے۔ امر تسر کے اخبار وکیل میں 5 جنوری 1916ء کو شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون اسرار خودی اور تصوف میں لکھتے ہیں:
حضرات صوفیا میں جو گروہ رسول اللہ ﷺ کی راہ پر قائم ہیں اور سیرتِ صدیقی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، میں اس گروہ کی خاکِ پا ہوں اور ان کی محبت سعادتِ دارین کا باعث تصور کرتا ہوں۔
(اقبال کے نثری افکار، عبدالغفار شکیل، ص: 93)
2۔ فکری اور نظری اساس
عہدِ جدید کے فکر کے مقابل جس تخلیقی ردعمل کی ضرورت تھی، وہ علامہ محمد اقبال کی انگریزی فلسفیانہ تحریروں میں نمایاں ہے۔ معاصر مسائل پر غور کرتے ہوئے اقبال نہ صرف مسلم فکری روایت کے تسلسل میں اپنی فکر کو آگے بڑھاتے ہیں بلکہ کمال بصیرت کے ساتھ ملت کے مستقبل کو بھی اپنے پیشِ نظر رکھتے ہوئے اپنی شاعری کو ملت کے مستقبل کی صورت گری کا ایک وسیلہ قرار دیتے ہیں۔
(1)مسلم روایت کا تسلسل
نہ صرف علامہ محمد اقبال کی اپنی فکر مسلم روایت کا تسلسل تھی بلکہ وہ عملاً بھی اس روایت کے احیا اور استحکام کے لیے کوشاں تھے۔ علامہ مصطفی المراغی شیخ جامعہ ازہر کے نام ایک خط میں علامہ نے لکھا:
لہذا میری تمنا ہے کہ آپ از راہِ عنایت ایک روشن خیال مصری عالم کو جامعہ ازہر کے خرچ پر ہمارے پاس بھیج کر ممنون فرمائیں تاکہ یہ شخص ہم کو اس کام میں مدد دے۔ چاہیے کہ یہ شخص علومِ شرعیہ اور تاریخ تمدنِ اسلامی میں ماہر ہو، نیز زبان انگریزی پر بھی قدرت کامل رکھتا ہو۔
(اقبال نامہ، مجموعہ مکاتیب اقبال، شیخ عطاء اللہ، ص: 224)
ó علامہ محمد اقبال نے اپنی تمام فکری تخلیقات کو مسلم روایت کا ہی تسلسل قرار دیا۔ ڈاکٹر نکلسن کے نام خط میں فرماتے ہیں:
میرا دعویٰ ہے کہ اسرار کا فلسفہ مسلمان صوفیاء اور حکماء کے افکار و مشاہدات سے ماخوذ ہے۔ (ایضاً، ص: 350)
(2) ملت کے مستقبل پر نظر
علامہ محمد اقبال کو اللہ نے وہ بصیرت عطا کی تھی کہ نہ صرف معاصر مسائل پر ان کی نظر تھی بلکہ وہ حادثہ جو پردہ افلاک میں ہے، وہ بھی ان کی نگاہ سے اوجھل نہ تھا۔ عالمی واقعات خصوصاً ملتِ اسلامیہ کے مستقبل کے بارے میں ان کا تجزیہ اور موقف حتمیت کی حد تک ثقاہت کا حامل تھا۔ معاصر حالات کے بارے میں فرمایا:
میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میرے دل میں ممالکِ اسلامیہ کے موجودہ حالات دیکھ کر بے انتہا اضطراب پیدا ہورہا ہے۔ ذاتی لحاظ سے، خدا کے فضل و کرم سے، میرا دل پورا مطمئن ہے۔ یہ بے چینی اور اضطراب محض اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ نسل گھبرا کر کوئی اور راہ اختیار نہ کرلے۔
(اقبال نامہ، مجموعہ مکاتیب اقبال، شیخ عطاء اللہ، ص: 163)
ó مستقبل میں اسلام کے کردار کے بارے میں فرمایا:
دنیائے جدید میں حالات اس سرعت سے بدل رہے ہیں کہ مستقبل کے متعلق پیشین گوئی تقریباً ناممکن ہے۔ اگر دنیائے اسلام سیاسی وحدت حاصل کرے (اگر ایسا ممکن ہو) تو غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ کیا ہوگا؟ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جغرافیائی حیثیت سے یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہونے کے لحاظ سے اور زندگی کے مشرقی و مغربی نصب العین کے امتزاج کی حیثیت سے اسلام کو مشرق و مغرب کے مابین ایک طرح کا نقطہ اتصال بننا چاہیے لیکن اگر یورپ کی نادانیاں اسلام کو ناقابلِ مفاہمت بنادیں تو کیا ہوگا؟
(حرفِ اقبال، لطیف احمد خان شیروانی، ص: 147)
ó علامہ محمد اقبال کو ملتِ اسلامیہ کے مستقبل کے بارے میں جو خصوصی بصیرت حاصل تھی، وہ قرآن حکیم میں ان کے زندگی بھر کے طویل غورو فکر کا نتیجہ تھا۔ مولانا شیخ غلام قادر گرامی کے نام خط میں لکھتے ہیں:
مثنوی کے تیسرے حصہ کا مضمون ہوگا: ’’حیات مستقبلۂ اسلامیہ‘‘ یعنی قرآن شریف سے مسلمانوں کی آئندہ تاریخ پر کیا روشنی پڑتی ہے اور جماعت اسلامیہ جس کی تاسیس دعوتِ ابراہیمی سے شروع ہوئی، کیا کیا واقعات و حوادث آئندہ صدیوں میں دیکھنے والی ہے اور بالآخر ان واقعات کا مقصود و غایت کیا ہے؟ میری سمجھ اور علم میں یہ تمام باتیں قرآن شریف میں موجود ہیں اور استدلال ایسا صاف و واضح ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تاویل سے کام لیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے قرآن شریف کا یہ مخفی علم بھی مجھ کو عطا کیا۔ میں نے پندرہ سال تک قرآن پڑھا ہے اور بعض آیات و سورتوں پر مہینوں بلکہ برسوں غور کیا ہے اور اتنے طویل عرصہ کے بعد مندرجہ بالا نتیجہ پر پہنچا ہوں۔
(اقبال، جناح اور پاکستان صفدر محمود، ص: 124)
(3) فکرو شاعری کا مقصد اصلاحِ ملت
علامہ محمد اقبال کی شاعری کا مقصد ملتِ اسلامیہ کی اصلاح اور مستقبل کی صورت گری ہے۔ جب مثنوی اسرار و رموز پر اعتراضات کیے گئے تو علامہ نے فرمایا:
یہ مثنوی کسی طرح لغو نہیں ہے۔ اگر اختلاف ضروری ہی ہے تو قرآن حکیم کے ارشاد: اذا مروا باللغو مروا کراما، کے مطابق اختلاف کرنا چاہیے۔ میرا مقصد صوفی تحریک کو مٹانا نہیں، عقلی اور مذہبی بیہودگیوں کو چھوڑ کر آخر کار فطرۃ اللہ کے قریب جاپہنچنا ہے، جس پر مذہب اسلام مبنی ہے۔
(اقبال کے نثری افکار، عبدالغفار شکیل، ص: 111)
ó سعید اکبر آبادی کے مطابق علامہ کی شخصیت اس اعتبار سے عدیم المثال تھی کہ ایک طرف وہ علوم جدیدہ کے ماہر اور مبصر نقاد تھے اور دوسری طرف علومِ اسلامیہ پر ان کی نگاہ مبصرانہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ عصرِ حاضر کو اسلامی حقائق سے آشنا کرنے کی ایک راہ علامہ نے خطبات کے ذریعے دکھائی ہے۔
(خطبات اقبال پر ایک نظر، سعید اکبر آبادی، ص: 84)
ó سید سلیمان ندوی کے نام خط میں لکھتے ہیں:
شاعری میں لٹریچر بحیثیت لٹریچر کے کبھی میرا مطمع نظر نہیں رہا کہ فن کی باریکیوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے وقت نہیں۔ مقصود صرف یہ ہے کہ خیالات میں انقلاب پیدا ہو۔
(اقبال نامہ، مجموعہ مکاتیب اقبال، شیخ عطاء اللہ، ص: 133)
ó علامہ محمد اقبال کی شخصیت عقل و عشق کا حسین امتزاج تھی۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا:
میں نے کبھی ایسا کوئی شعر نہیں کہا کہ جسے میں نے قلب میں محسوس نہ کیا ہو اور محض عقل کے زور سے کہہ دیا ہو یعنی میرے اشعار میں فکر اور جذبہ دونوں کا امتزاج پایا جاتا ہے۔
(مجالس اقبال، جعفر بلوچ، ص: 84)
ó عملی جدوجہد کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا:
میں انگریزی، اردو، فارسی میں برنگ نثر بھی اپنے خیالات کا اظہار کرسکتا تھا لیکن یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ طبائع نثر کی نسبت شعر سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ لہذا میں نے مسلمانوں کو زندگی کے صحیح مفہوم سے آشنا کرنے، اسلاف کے نقشِ قدم پر چلانے اور ناامیدی، بزدلی اور کم ہمتی سے باز رکھنے کے لیے نظم کا ذریعہ استعمال کیا۔ میں نے پچیس سال تک اپنے بھائیوں کی مقدور بھر ذہنی خدمت کی۔ اب میں ان کی بطرزِ خاص عملی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کررہا ہوں۔
(گفتارِ اقبال، محمد رفیق افضل، ص: 16)
ó اپنی کتاب جاوید نامہ کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا:
یہ حقیقت میں ایشیا کی ڈیوائن کامیڈی ہے۔ جیسے ڈینٹے کی تصنیف یورپ کی ڈیوائن کامیڈی ہے۔ اس کا اسلوب یہ ہے کہ شاعر مختلف ستاروں کی سیر کرتا ہوا مختلف مشاہیر کی روحوں سے مل کر باتیں کرتا ہے۔ پھر جنت میں جاتا ہے اور آخر میں خدا کے سامنے پہنچتا ہے۔ اس تصنیف میں دورِ حاضر کے تمام جماعتی، اقتصادی، سیاسی، مذہبی، اخلاقی اور اصلاحی مسائل زیر بحث آگئے ہیں۔ اس میں صرف دو شخصیتیں یورپ کی آئی ہیں: اول کچنر، دوم نیتشے۔ باقی تمام شخصیتیں ایشیا کی ہیں۔ ڈینٹے نے اپنا رفیقِ سفر یا خضرِ طریق ’’ورجل‘‘ کو بنایا تھا۔ میرے رفیقِ سفر یا خضرِ طریق، مولانائے روم ہیں۔
(ایضاً، ص: 244)
ó عالم اسلام کی عمومی حالتِ زوال کو دیکھتے ہوئے اقبال اکثر اس امر کا اظہار کرتے کہ مسلمانوں کو ان کے مقام سے آشنا کرنے کے لیے عملی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ یہاں وہ اکثر اپنی شاعری کو بھی ہیچ سمجھتے:
اسپین کیا، مسلمان اپنی ساری تاریخ سے بے خبر ہیں۔ یہ شعرو شاعری کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں! کاش میں نے شاعری نہ کی ہوتی۔
(اقبال کے حضور، سید نذیر نیازی، ص: 272)
3۔ عملی اساس
بطور ایک سماجی اور سیاسی مصلح علامہ محمد اقبال نے قوم کی رہنمائی بھی کی اور مسائل کے حل کے لیے تجاویز بھی دیں۔ یہ پہلو پھر تین جہتوں کا حامل ہے۔ اقبال کی شخصیت ایسی عملی سیاسی بصیرت کی مظہر ہے جس نے انتہائی ناگفتہ بہ حالات میں بھی ملت کے لیے اس مستقبل کی پہلے سے پیش بینی کی جس راستے پر بہت سے مقتدر قائدین بعد میں گامزن ہوئے۔ ذاتی حوالے سے بھی علامہ کی شخصیت اسلام کی دینی اور روحانی تعلیمات کا ایک عملی نمونہ نظر آتی ہے۔ عملی سیاست میں بھی اقبال کا کردار اسی عبقریت کا مظہر ہے۔
(1)سیاسی بصیرت
مسلمانانِ برصغیر کی عملی اور نظریاتی میدان میں سیاسی رہنمائی کا جو کردار علامہ محمد اقبال نے ادا کیا تھا وہ اس خداداد بصیرت سے مملو تھا جس کی کوئی نظیر اس دور میں نہیں ملتی۔ اقبال نے ہراہم سیاسی موقع پر قوم کی صحیح سمت میں رہنمائی کی۔ اقبال کے اسی کردار کی وجہ سے قائداعظم نے اقبال کو مسلم ہند کی احیائی جدوجہد کا مفکر قرار دیا:
Every great movement has a philosopher and iqbal was the philosopher of the National Renaissance of Muslim India. (Discourses of iqbal, shahid hussain Razzaqi)
ó علامہ محمد اقبال کی سیاسی جدوجہد کا مطالعہ اسی پہلو کو مزید روشن کرتا ہے۔ خطبہ الٰہ آباد کے موقع پر فرمایا:
میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلام، اس کے نظامِ سیاست و قانون، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کے ادب کے مطالعہ میں صرف کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ روحِ اسلام کے ساتھ مسلسل تعلق کی بدولت جس کا اظہار وقت کے ساتھ ہورہا ہے، میرے اندر اسلام کو ایک اہم عالم گیر حقیقت کی حیثیت سے دیکھنے کی بصیرت پیدا ہوگئی ہے۔
(علامہ محمد اقبال کا خطبہ الٰہ آباد، شفیق ملک ندیم، ص: 120)
ó علامہ محمد اقبال کے اس وصف کا اندازہ اغیار کو بھی تھا۔ لارڈ لوتھین نے ایک موقع پر کہا:
عالم اسلام ہی میں نہیں، تمام مشرق میں اقبال جیسا اثر انداز مفکر اور کوئی نہیں۔ اقبال کے افکار تاریخِ عالم کا رخ بدل دیں گے۔ سیاسی لوگ نہیں جانتے کہ اقبال کی طرح کے شاعر کس قدر موثر ہوسکتے ہیں،
(اقبال فراموشی، فتح محمد ملک، ص: 25)
محمد دین تاثیر کے بقول: اقبال کی جاودانیت وہی ہے جو قرآن حکیم کی جاودانیت ہے کیونکہ کلامِ اقبال تفسیرِ کلامِ الہٰی ہے۔ جاودانی مگر عملی پیغامات کی یہ بنیادی خصوصیت ہے کہ ان میں ماحول کی مطابقت بھی ہوتی ہے اور اس سے بغاوت بھی اور یہ انقلابی بغاوت ایک مخصوص ماحول کو بدلنے کے ساتھ ساتھ ایک عالمگیر انقلاب کی بنیاد بھی ڈالتی ہے۔
(اقبالیاتِ تاثیر، افضل حق قرشی، ص: 58)
ó مولانا سیدابوالحسن علی ندوی نے اقبال کی اس عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا:
میں سمجھتا ہوں کہ اقبال وہ شاعر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مطابق بعض حکم و حقائق کہلوائے ہیں جوکسی دوسرے معاصر شاعر و مفکر کی زبان سے نہیں ادا ہوئے۔ یہ سیاسی بالغ نظری اور بلند ہمتی جس کی نظیر اس دور میں عالمِ اسلام میں مشکل سے ملے گی، مملکت پاکستان کی بنیاد ہے جس پر اس عظیم ترین اسلامی ریاست کی تعمیر ہوئی تھی اور اس کو اسلامی زندگی کی ایک تجربہ گاہ قرار دیا گیا۔
(اقبال فراموشی، فتح محمد ملک، ص: 52)
جب مسلمانوں کے مستقبل کو عملاً محفوظ کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا تو تصورِ پاکستان کو حقیقت میں بدلنے کی تحریک کی قیادت کے لیے علامہ اقبال نے صرف قائداعظمؒ کا انتخاب کیا اور برصغیر کی سیاسی قیادت کے لیے قائداعظم ہی کو واحد اہل رہنما قرار دیتے ہوئے فرمایا:
مسٹر جناح ہی مسلمانوں کے اصل لیڈر ہیں اور میں تو ان کا ایک معمولی سپاہی ہوں۔
(اقبال کے آخری دو سال، عاشق حسین بٹالوی، ص: 532)
(2)روحانی ومذہبی پہلو
علامہ محمد اقبال کی فکر میں جن مذہبی اور روحانی اقدار کا ذکر موجود ہے وہ اقبال کی شخصیت کا بھی زندہ اور فعال حصہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے فعال تعلقِ بندگی اور پھر زندگی میں اس کے اثرات کی موجودگی اقبال کے ہاں بآسانی دیکھی جاسکتی ہے۔
ó سرکشن پرشاد کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: خدا کے فضل و کرم سے تہجد سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دعا کروں گا کہ اس وقت عبادتِ الہٰی میں بہت لذت حاصل ہوتی ہے۔ کیا عجب ہے کہ دعا قبول ہوجائے۔
(اقبال نامہ، مجموعہ مکاتیب اقبال، ص: 477)
ó زندگی میں تسلیم و رضا کی روش اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
عجب کشمکش کی حالت ہے مگر شکایت نہیں کہ ہمارے مذہب میں شکایت کفر ہے۔
(ایضاً، ص: 70)
ó میں نے اب تک اپنے معاملات میں ذاتی کوشش کو بہت کم دخل دیا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو حالات کے اوپر چھوڑ دیا ہے اور نتیجے سے خواہ وہ کسی قسم کا ہو، خدا کے فضل و کرم سے نہیں گھبرایا۔ اس وقت بھی قلب کی کیفیت یہی ہے کہ جہاں اس کی رضا لے جائے گی، جاؤں گا۔
(ایضاً، ص: 493)
(3)عملی سیاسی جدوجہد
علامہ محمد اقبال صرف شاعر، مفکر یا علمی شخصیت ہی نہیں تھے بلکہ انھوں نے عملی سیاسی میدان میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اقبال کا سیاسی کردار آئینی، اصولی اور حقیقت پسندانہ تھا۔ آئینی و قومی مسائل پر حقیقت پسندانہ موقف اختیار کرتے ہوئے فرمایا:
مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر ہندو ہم پر حکومت کریں بشرطیکہ ان میں حکومت کرنے کی اہلیت اور شعور ہو لیکن ہمارے لیے دو آقاؤں کی غلامی ناقابلِ برداشت ہے۔ ہندو اور انگریزوں میں سے صرف ایک ہی کا اقتدار گوارا کیا جاسکتا ہے۔
(حرفِ اقبال، لطیف احمد خان شیروانی، ص: 156)
ó قومی مسائل پر مسلمان قائدین خصوصاً مذہبی قائدین کی بے بصیرتی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:
تاسف کا مقام ہے کہ ہمارے بعض لیڈر، جن میں بعض علمائے دین بھی شامل ہیں، مسئلہ انتخاب کو محض نمائندگی کا طریقہ کار تصور کرتے ہیں اور بس۔ جہاں تک میں نے مسلمانانِ ہند کی گزشتہ تاریخ اور ایشیائی اقوام کے موجودہ امیال و عواطف اور مغربی اقوام کی سیاسی ریشہ دوانیوں پر غور کیا ہے، مجھے اس بات کا کامل یقین ہے کہ ابھی ایک عرصہ تک مسلمانانِ ہند کا مستقبل جداگانہ انتخاب سے وابستہ ہے۔
(گفتارِ اقبال، محمد رفیق افضل، ص: 164)
ó مُلا کا ذہن یوں عقیم ہے کہ صدیوں کی فرسودہ اور لاحاصل بحثوں میں الجھ کر اس کی فکری صلاحیتیں ختم ہوچکی ہیں۔ وہ نہیں سمجھتا کہ اسے جن عقائد پر سختی سے اصرار ہے، اسلام نے ان کا رشتہ زندگی سے کس طرح جوڑا اور ان سے فی الحقیقت کیا مقصود ہے۔
(اقبال کے حضور، سید نذیر نیازی، ص: 283)
علامہ محمد اقبال نے کبھی قومی مسائل پر کوئی ایسا موقف اختیار نہیں کیا جو زمینی حقائق کے خلاف ہو یا مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے تحفظ کا ضامن نہ ہو۔ جمہوری انداز سے سوچتے ہوئے جہاں وہ مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل مسلمان مملکتوں اور ہندو اکثریت کے علاقوں پر مشتمل ہندو ریاستوں کے قیام کا جمہوری تصور اجاگر کرنے میں مصروف تھے وہاں وہ ہندو قوم اور اچھوت قوم کے حقِ خود اختیاری کو بھی کھلے دل سے تسلیم کررہے تھے۔ وہ خود بھی آزاد رہنا چاہتے تھے اور دوسروں کی آزادی اور خود مختاری کا حق بھی تسلیم کرتے تھے۔ ان کے نزدیک پورے ہندوستان پر اسلام کا بزور شمشیر غلبہ ایک غیر اسلامی اور فاشسٹ تصور تھا۔
(اقبال فراموشی، فتح محمد ملک، ص: 159)
عملی سیاسی مسائل کے حل کے لیے اقبال نے جو موقف اور حکمت عملی اختیار کی وہ اقبال کے ایک عملیت اور حقیقت پسند سیاسی رہنما کے تشخص کو سامنے لاتی ہے۔
حاصلِ کلام یہ ہے کہ دورِ جدید میں انسان جن فکری اور عملی مسائل سے گزر رہا ہے ان کے حل کے لیے ایک جامع فکری نظام کی ضرورت ہے۔ روایت، جدیدیت اور مابعد جدیدیت تبدیلیوں کے تناظر میں اقبال کی فکر آج کے جدید انسان کی فکری اور عملی ضرورتیں پوری کرتی ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ جدیدیت کے جواب میں اقبال مسلم دنیا کی واحد نمائندہ آواز ہیں۔ مذکورہ بالا تینوں حوالوں سے اقبال کی فکر اور شخصیت ہمارے لیے قومی اور ملی سطح پر غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔